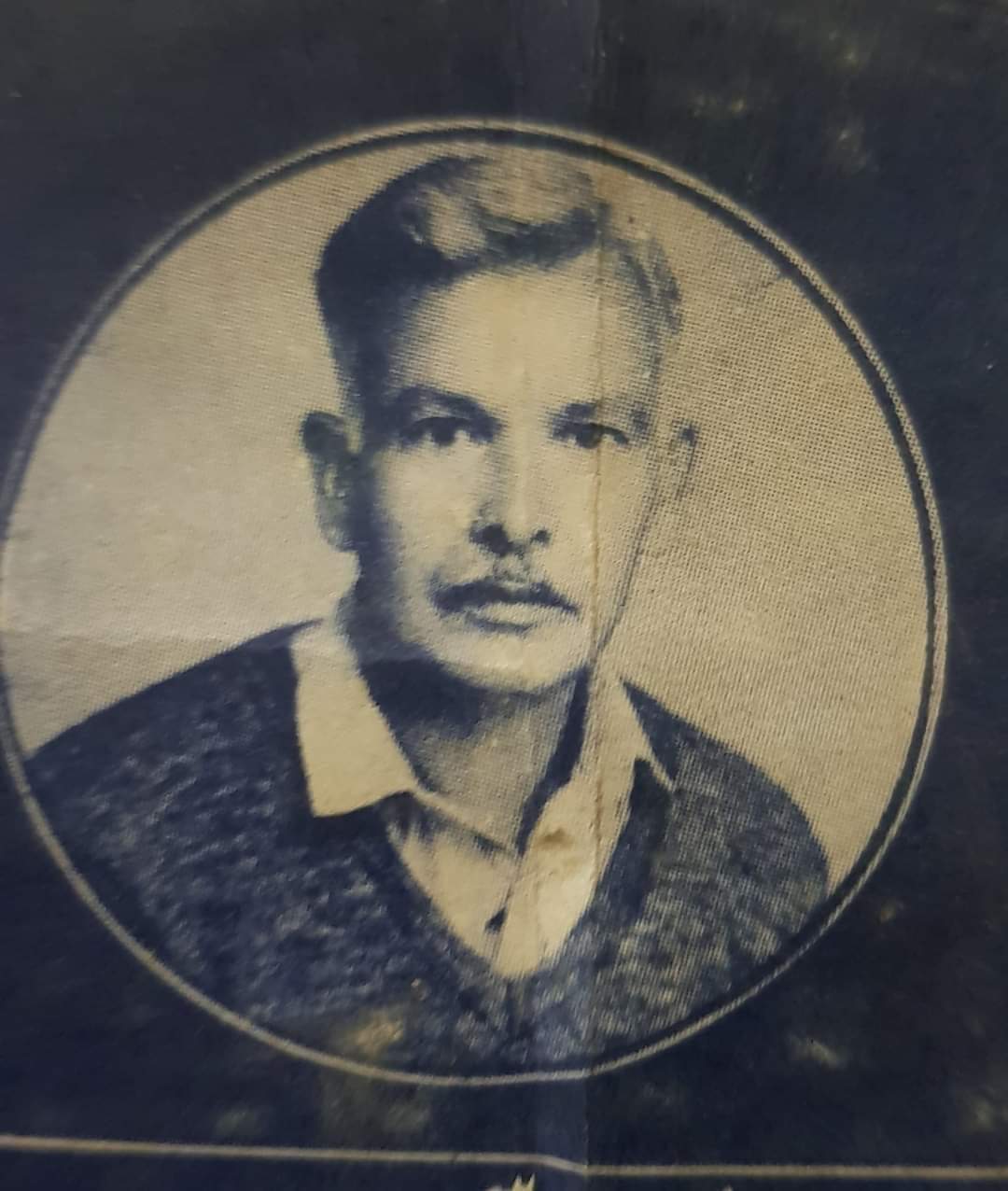” آپ نے بمبئی میں ‘مایا مچھندر’ دیکھی۔ اب بتائیے، وہ جیسی ہے ویسی ہی پیش کی گئی تو کیا لوگ اسے پسند کریں گے؟” فتےلال جی بڑی سنجیدگی سے سوال کر رہے تھے۔ دوسرے دن سویرے، داملے جی، فتےلال جی، دھایبرجی وغیرہ سب لوگ ہمارے ‘پربھات’ کے کارخانے میں بحث کر رہے تھے۔ تب بمبئی میں میرے کئے گئے فیصلے پر فتے لال جی نے شبہ ظاہر کیا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر آج ہی یہ بےیقینی کیوں؟
میں نے تڑاخ سےجواب دیا، “آپ کی رائے بھی گووندراؤ اور بابوراؤ جیسی ہی ہے تو جائیے، بمبئی تار دیجیے اور ‘مایا مچھندر’ کی ریلیز آگے دھکیل دیجیے۔ اس کی کاپی یہاں واپس منگا لیجیے۔ اس میں جو بھی تبدیلی کرنی ہو، شوق سےکیجیے۔” سبھی چپ رہے۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔
اس واقعے کے بعد دوسرےدن داملےجی اور فتےلال جی کے واقف ایک سجن بابوراؤ ٹول کسی سادھو بابا کو کمپنی میں لے آئے۔ ان باباجی کی عظمت کی انہوں نے تعریفیں کیں۔ ان کا نام تھا دادامہاراج۔ سبھی ساجھےدار ان کے چرن چھونے کے لیے لپکے۔ میں دور سے ہی تماشا دیکھتا رہا۔
بابوراؤ ٹول میرے پاس آ کر کہنے لگے، “شانتارام بابو، آگے بڑھیےاور آپ بھی چرن چھو آئیے۔ آپ کےمن میں جو بھی سوال ہو، پوچھ لیجیے۔”
“لیکن مجھے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے،” میں نے کہا۔
“اجی آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ وہ آپ کی کمپنی میں آئے ہیں۔ کمپنی میں آنے والے دوسرے لوگوں سے جس طرح ملتے ہو، نمسکار کرتے ہو، ویسا بھی نہیں کر سکتے آپ؟ محض ایک رسمی طور پر تو ملیے نا ان سے۔”
ٹول جی کی دنیاداری کچھ تو سمجھ میں آ گئی۔ ایک دم ہچکچاہٹ سے میں ان سادھو مہاراج کے سامنے گیا اور کھڑے کھڑےہی میں نے انہیں پرنام کیا۔
یہ دیکھ کر کہ پھربھی میں کچھ بول نہیں رہا ہوں، ٹول صاحب نے سادھو بابا سے کہا، “شانتارام بابو جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پربھات فلم کمپنی مستقبل میں کیسی چلےگی؟”
دادا مہاراج نے پوری سنجیدگی سے کہا، “انہوں نے ٹھیک سے چلائی تو ٹھیک ہی چلے گی۔”
مجھے اس بچگانے جواب پر زور کی ہنسی آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ہنسی کو روکا۔
کچھ دیر بعد دادا مہاراج چلے گئے اور تب تک روکی رکھی میری ہنسی زور سے ابھر آئی۔ میں نے ہنستے ہنستے کہا، “بھئی خوب رہی! کہتے ہیں، ہم نے ٹھیک چلائی تو کمپنی ٹھیک چلےگی! لیکن یہ بتانے کے لیے ان سادھو بابا کی کیا ضرورت ہے؟”
میرا دادا مہاراج کی اس طرح کِھلی اڑانا دیگر لوگوں کو قطعی نہیں بھایا۔
‘مایا مچھندر’ بمبئی میں ریلیز ہو گئی اور اس نے بازی جیت لی۔ لوگوں کو ‘مایا مچھندر’ بہت ہی پسند آئی ہے، یہ خبر وضاحت سے دینے والا بابوراؤ پینڈھارکر کا تار آیا۔ فلم کے بارے میں میری چھٹی حس ایک دم صحیح ثابت ہوئی۔ بابوراؤ پینڈھارکر کولہاپور واپس آئے اور انہوں نے بِنا کچھ کہے میری پیٹھ تھپتھپائی۔ جن کی انگلی تھام کر میں نے اس فلمی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا، ان سے اس طرح خاموش شاباشی پا کر میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت مانا۔
یہ فلم نہ صرف بمبئی میں، بلکہ سارے دیش، سبھی جاتی کے لوگوں کو بہت ہی پسند آئی۔ اس کا اینڈ دیکھ کر تو لوگ گدگدا جاتے تھے۔
گورکھ ناتھ اپنی غار میں واپس آتا ہے اور دیکھتا کیا ہےکہ اس کے گروجی مچھندر ناتھ وہیں سمادھی جمائے بیٹھے ہیں! تذبذب میں مبتلا گورکھ اپنے گروجی سے پوچھتا ہے، “ابھی کچھ لمحے پہلے تو آپ اس ستری (عورت) ریاست میں تھے اور ابھی آپ یہاں ہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ وہ یا یہ؟”
گورکھ ناتھ کے اس سوال کا معقول جواب مکالمہ لکھتے وقت ہم میں سے کوئی نہیں کھوج پایا تھا۔ ہمارے ڈائیلاگ رائٹر نے اس پر لمبا بھاشن لکھ مارا تھا، لیکن اسے سننے کے لیے ناظرین تھئیٹر میں ہرگز نہ رُکتے۔ ہم سب نے کافی سوچا لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ آخر فلم میں گورکھ ناتھ کے اس سوال کو ویسا ہی لاجواب چھوڑ کر ہم لوگ باقی شوٹنگ میں جُٹ گئے۔ سوچا، شاید آگے چل کر اس کا جواب اپنے آپ اُبھر آئے گا۔
ساری فلم کی شوٹنگ پوری ہو گئی اور اب اس آخری سین کی شوٹنگ کا دن آ گیا۔ اب تو گورکھ ناتھ کےاس سوال کاجواب مزید ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ کیا کریں، کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ آخر ہار کر میں نے مچھندر ناتھ کے منھ سے ‘چت بھی میری، پٹ بھی میری’ سٹائل میں گول مول جملہ کہلوایا :
گورکھ پوچھتا ہے،”گروجی، یہ سچ ہے، یا وہ سچ ہے؟”
“بیٹا گورکھ ناتھ، یہ بھی سچ ہے اور وہ بھی سچ ہے۔ تمہارے لیے یہ سچ، وہ مایا۔” مچھندر ناتھ بڑی گمبھیرتا سے جواب دیتا ہے۔ یہ جملہ مچھندر ناتھ سے کہلوایا۔ تب سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی بڑی بات کہلوائی ہے۔ لیکن ناظرین نے اس جملے میں مہان فلسفیانہ نظریہ پایا۔ کئی جذباتی ناظرین نے خط بھیج کر مجھےدلی مبارکباد دی کہ اتنا گہرا،سنجیدہ فلسفیانہ نظریہ میں نے بالکل آسان الفاظ میں آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا۔
لگ بھگ اسی وقت، ‘پربھات’ کی طرف سے ہم نے ‘سیتا کلیانم’ نامی تمِل فلم بنائی۔ اس کی ڈائریکشن بابوراؤ پینڈھارکر نےکی۔ اس کام کرنے کے لیے سبھی لوگ مدراس سے لائے گئے تھے۔ کچھ ٹیکنیشین بھی وہیں سے آئے تھے۔ لیکن پروڈکشن ‘پربھات’ کی ہی تھی۔ یہ فلم مدراس صوبے میں کافی مقبول ہو گئی تھی۔
‘مایا مچھندر’ کا کام شروع ہونے سے کچھ دن پہلے اگفا کمپنی کے ہندوستان میں مشہور لائیڈن اور ریگے کولھاپور آئے تھے۔ رنگین فلم بنانے کا ایک نیا بائی پیک سسٹم انہوں نے تیار کیا تھا۔ انہوں نےاس سسٹم کی جانکاری دینے والی مشینری ہمیں دی۔ اس بائی پیک سسٹم میں کیمرے میں ایک ہی وقت میں نیگیٹو کے دو فیتے چلانے پڑتے تھے۔ ایک نیگیٹو نارنجی رنگ کے لیےاور دوسری نیلے رنگ کے لیے۔ دونوں نیگیٹوز کو ایک ہی ساتھ فلمانا پڑتا تھا۔ کیمیائی عمل تو بلیک اینڈ وائٹ نیگیٹو پر جیسا ہوتا ہے، ویسا ہی کرنا پڑتا تھا۔ بعد میں ایک ہی پازیٹو فلم پر ایک طرف نارنجی اور دوسری جانب نیلے کے نیگیٹو کے پرنٹ اس طرح لینے پڑتے تھے اور اس طرح ریلیز کا پرنٹ تیار کیا جاتا تھا۔ اس سسٹم میں پیلا رنگ آزاد روپ میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نارنجی رنگ میں پیلی چمک آ جاتی تھی، اتنا ہی پیلا رنگ موجود ہوتا تھا۔ اس بائی پیک سسٹم کا استعمال کر جرمنی میں فلمایا ایک فلم رول بھی ہم نے پردے پر دیکھا۔ اس وقت تو ہم سب کو وہ بہت ہی پسند آیا۔
بھارت میں پہلی رنگین فلم بنانےکا یہ موقع نہ کھونے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ کیمرے میں جڑواں فلم چڑھانے کا انتظام کرنے اور جرمنی سے رنگین نگیٹو آنے میں دو تین مہینے کا وقت لگنے والا تھا، لہٰذا اس بیچ خالی ہاتھ بیٹھے رہنے کے بجاے ہم لوگوں نے ایک فلم بنانے کا سوچا۔ مہاراشٹر فلم کمپنی کی ‘سنگھ گڈ’ خاموش فلم کافی مقبول ہو چکی تھی۔ اسی خاموش فلم کو بولتی فلم میں بدلنے کا ہم لوگوں نے ارادہ کیا۔ مشہور مراٹھی ناول نگار ہری نارائن آپٹے کے ناول ‘گڈ آلا، پن سنگھ گیلا’ کے مکمل حقوق ہم نے خرید لیے۔ اس فلم کو صرف مراٹھی میں ہی بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا۔
اسی وقت کولہاپور میں مراٹھی ادبی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک مشاعرے میں بیٹھے بیٹھے میرے من میں ایک وچار آیا۔ میں نے سبھی شاعروں کو اپنی کمپنی میں محبت سے مدعو کیا۔ کیشو کمار عرف اترے، شاعر یشونت، گریش (مراٹھی کے مشہور ناٹک کار وسنت کانیٹکر کے پتاجی)، سوپان دیو چودھری، مایدیو، سنجیونی مراٹھے وغیرہ مشہور شاعر ہمارے سٹوڈیو آئے۔ انہیں کیمرے کے سامنے کھڑا کر ہم نے ان سے ان کی کچھ نظمیں پڑھوائیں، اس کو فلما لیا اور ساؤنڈ ریکارڈنگ بھی کر لی۔ لیکن انہیں پردے پر جوں کا توں پیش نہیں کیا۔ ہمارے کلاکاروں سے مناسب بھیس میں ان نظموں کے مصرعوں کے مطابق خاموش اداکاری (مائم) کرائی۔ مثال کے لیے: شاعر یشونت کی نظم ‘نیاہاریچا وکھت جھالا میترنی بگی بگی چال’ پر ایک کسان لڑکی باجرے کی روٹیوں کی ٹوکری سر پر لیے اپنے پتی کو ناشتہ کرانے کے لیے بڑی لپک لچک کر کھیت کی طرف جا رہی ہے، ایسا سین ہم نے فلمایا۔ اسی طرح اترےکی ‘پرٹا، ییشل کدھی پرتون’- طنزیہ نظم پر ایک دھوبی اپنے گدھے پر میلے کپڑوں کی گٹھری لادے جا رہا ہے، ایسا منظر ہم نے فلمایا۔
اس مشاعرے کی ڈاکیومنٹری ہم نے ‘سنگھ گڈھ’ فلم کے ساتھ پیش کی۔ ناظرین نے اس نئے آئیڈیا کا اچھا استقبال کیا۔ نظم لکھتے وقت اہلِ نظر کے سامنے جو متاثرکن سین تھا، اسے فلمی پردے پر سچ دیکھ کر بہت لطف حاصل ہونے کی بات کی سبھی شاعروں نےخط لکھ کر ہمیں اطلاع دی۔
‘ایودھیا کا راجا’ ہماری پہلی ہندی بولتی فلم تھی۔ اسے استثنیٰ مان لیا جائے تو ہماری سبھی خاص فلمیں اچھی طرح کامیاب رہی تھیں۔ کمپنی میں خوشی اور جوش ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ لیکن اب ہمیں ایک کمی ستانے لگی تھی۔ بمبئی میں سبھی سٹوڈیوز میں آج کل بجلی کے طاقتور بلبوں کی تیز روشنی میں شوٹنگ ہونے لگی تھی۔ ہم نے کولھاپور کی بجلی کمپنی کے اہلکاروں کے پاس جا کر پوچھ تاچھ کی کہ کیا فلم میکنگ کے لیے ضروری بجلی وہ ہمیں دے سکیں گے؟ لیکن انھوں نے ٹکا سا جواب دیا، “دوسرے زیادہ غیرمعمولی کاموں کے لیے بجلی کا استعمال کرنا ہے، اس لیے فلم کے لیے بجلی دینا ممکن نہیں ہو گا۔”
ہم سب کے سامنے فیصلہ کن مشکل منھ کھولے کھڑی تھی: سورج کی کرنوں کو منعکس کرنے کے پرانے طریقے کے مطابق ہی شوٹنگ کرنے کے لکیر کے فقیر بنے رہیں، یا آج اور سب لوگوں کی طرح شوٹنگ کے لیے بجلی کا استعمال کرنا شروع کریں؟
دنیا سے پیچھے رہنا ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ من میں وچار آنے لگا کہ کولہاپور میں اگر بجلی کی سہولت میسر نہیں تو کیوں نہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ میسر ہو؟ بس، اپنی فلم کمپنی کو پُونا، بمبئی جیسے کسی شہر میں لے جانے کا ارادہ پکا ہونے لگا۔
اور اسی وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی ‘پربھات’ کمپنی کو دوسرے شہر لے جانے کا ارادہ پکا کر ہی ڈالا۔ بات یہ ہوئی کہ ایک دن کولہاپور کے راجا، راجارام مہاراج، ان کی بہن اکا صاحب مہاراج، ماتاجی آئی صاحب مہاراج وغیرہ، راج خاندان کے لوگ سٹوڈیو میں ہماری شوٹنگ دیکھنے کے لیے آئے۔ جاتے جاتے مہاراج نے مجھے راج محل آ کر ملنے کو کہا۔
میں راج محل پہنچا۔ مہاراج نے ہماری کمپنی کا حال پوچھا۔ ‘پربھات’ کے سبھی ساجھے داروں کے نام پوچھے۔ بعد میں باتوں باتوں میں انھوں نےکہا، “شانتارام بابو، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہےکہ کمپنی اچھی طرح چل رہی ہے، لیکن آپ کےساجھےداروں میں دو بامن ہیں، داملے اور کُلکرنی۔ بامن جاتی کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے فائدے کے پرے دیکھ نہیں سکتی۔ آپ سب لوگ اوپر اٹھنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں، تب تک تو یہ لوگ آپ سے ٹھیک طرح پیش آئیں گے۔ لیکن آپ کی پانچوں انگلیاں گھی میں آتے ہی آپ کا سر کڑاہی میں ڈالنے سے یہ لوگ کبھی نہیں چوکیں گے!”
مہاراج کے برہمن بیزار رویے کے بارے میں مَیں نے سنا تو تھا، اب بات سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے میرےساتھیوں کے بارےمیں جو نامناسب باتیں کہی تھیں، مجھے قطعی نہیں بھائیں۔ میں نےانھیں صاف کہہ دیا، “داملےجی اور کلکرنی جی برہمن بھلے ہی ہوں، آپ بتاتے ہیں، ویسے ہرگز نہیں ہیں!”
“میری بات آپ کو آج نہیں اچھی لگی شاید، لیکن کچھ سال بعد آپ خود تجربہ کریں گے اسے!”
مہاراج کی باتیں سن کر میرے من میں شُبہ جاگا کہ کہیں یہ ہم لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی تو کوشش نہیں کر رہے ہیں؟
میں کمپنی میں واپس آ گیا۔ راج محل میں ہوئی ساری باتیں ساتھیوں کو بتا دیں اور اپنا پیغام بھی واضح کر دیا۔ ایسی حالت میں مہاراج نے چاہا تو وہ ہماری کمپنی کو چٹکیوں میں تباہ کر سکتے تھے!
لہٰذا ہم سب نے مکمل باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا کہ کولھاپور سے کمپنی کا بوریا بستر اٹھا کر بمبئی کےپاس پُونا شہر میں پربھات فلم کمپنی کو نئے سرے سے شروع کیا جائے۔
ڈھیلاپن اور سستی ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ سٹوڈیو کے قابل جگہ کی کھوج کے لیے ہم نے بابوراؤ پینڈھارکر کو پُونا بھیجا۔ انہوں نے ڈیکن جمخانہ کے آگے ایرنڈونا رستے پر سردار ناتو کی ایک کافی بڑی کھلی جگہ پسند کی۔ جگہ لگ بھگ آٹھ ایکڑ تھی۔ بابوراؤ نے زمین کا سارا حال ہمیں لکھ بھیجا۔ جگہ پسند کرنے کے لیے ہم سب کو انھوں نے پونا بلا لیا۔
پُونا میں اس جگہ پر پہنچتے ہی ہم بہت مطمئن ہوئے۔ ‘پربھات’ کے قیام کے وقت سے ہی من میں ’پربھات نگر’ بسانے کی جو بات گہری پَیٹھ چکی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے یہ جگہ بہترین تھی۔ پھر اس کے آس پاس بھی لگ بھگ سو دو سو ایکڑ زمین خالی پڑی تھی۔ آگے چل کر اسے بھی خریدا جا سکتا ہے اور پربھات نگر بسانے کا سپنا سچ کیا جا سکتا ہے، یہ وچار مجھ پر حاوی ہو گیا اور بِنا بھاؤتاؤ کیے ہی ہم نے وہ زمین خرید لی۔ پُونا میں ایک انجینئر تھے پَوار۔ انہیں سٹوڈیو اور دوسرے شعبوں کی پوری جانکاری دی اور اس کے مطابق پلان بنانے کے لیےکہا۔ ان کےکام پر داملےجی دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ وہ بیچ بیچ میں پُونا جاتے اور سٹوڈیو کےتعمیری کام پر نظر رکھتے تھے۔
اب تک رنگین فلم کے لیے ضروری ساری مشینری اور سازوسامان، جڑواں نگیٹو وغیرہ ہمیں مل گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انگریزی میں معلوماتی کتابیں بھی آئی تھیں۔ ان سب کو میں نے پورے دھیان سے پڑھا اور ان میں دی گئی ہر بات کا باریکی سے مطالعہ کیا۔ پھر وہ ساری جانکاری میں نے مراٹھی میں دھایبر، فتے لال جی، داملےجی وغیرہ سب کو ٹھیک طرح سے سمجھا دی۔
رنگینی کاخیال کر کمپنی کےکلاکاروں کو پوشاکیں دیں، اور جانکاری کی کتابوں میں دی گئی ہر بات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہوئے تجربے کی خاطر تھوڑی شوٹنگ کی۔ اس جڑواں نیگیٹو پر کیمیکل کا عمل پورا کر رنگین پرنٹ نکالنے کے لیے انہیں جرمنی بھجوا دیا۔
رنگین فلم کے روپ میں ایک نئی ست رنگی دنیا کا علاقہ ہمارے سامنے کھل گیا۔ رنگین فلم کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی قدیم موضوع کو ہی لیا جائے۔ اس لیے ‘کیچک وَدھ’ کی حکایت کو ہم لوگوں نے چنا۔ مہابھارت کی اسی کہانی پر بابوراؤ پینٹر نے ایک فلم ڈائریکٹ کی تھی۔ اس کا مجھ پر بہت اثر پڑا تھا اور اسی لیے میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تھا۔ اس کہانی کے ذریعے سے قدیم سیاسی سوالوں کو ڈھنگ سے پھر ایک بار عوام کے سامنے ابھارا جا سکتا تھا۔ آدرشی فلم بنانے کے میرے اپنےسٹائل میں بھی یہ درست بیٹھتا تھا۔ ہم نے بھی اس فلم کا نام ‘سیہ رنگھری’ رکھنا ہی طے کیا۔
میں نے ایڈیٹنگ شروع کی۔ رنگین پرنٹ کے لیے فلم کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک سے معلوم نہ ہونے کے کارن میں نے ہر سین کی علیحدہ ایڈیٹنگ کر اسے چھوٹی چھوٹی گراریوں میں باندھا۔ اس طرح کئی گراریاں بن گئیں۔ ہر چھوٹی گراری کا ہماری تجربہ گاہ میں ہی بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ تیار کیا اور انہیں جوڑ کر ہم نے فلم کو تجرباتی روپ میں پردے پر دیکھا۔ ایک ہی رنگ کی ہونے کے کارن اس فلم پٹی پر نقش سین پردے پر صاف دکھائی نہیں دیے، لہٰذا فلم کا کُل اثر دیکھنے والوں پر کیا پڑے گا، ہم لوگ ٹھیک سے بھانپ نہ سکے۔
اب اس جڑواں نیگیٹو سے رنگین کاپی نکالنے کا وقت آ گیا تھا۔ آج تک اس کیمیائی عمل کا سارا کام داملےجی دیکھا کرتے تھے، لہٰذا اس کام کے لیے جرمنی جانےکی ذمےداری انھی کو سونپی گئی۔ وہ سفر کی تیاری میں جُٹ گئے۔ ان کا پاسپورٹ بن کر آ گیا۔
لیکن ایک دن سویرے ہی داملے جی میرے پاس آئے اور بولے، “شانتارام بابو، جرمنی آپ ہی جائیے۔ ادھر انگریزی میں باتیں کرنا مجھ سے ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا!”
میں نے ہنس کر کہا، “میں بھی کون بچپن سے انگریزی بول پاتا ہوں؟ ویسے انگریزی بات چیت آپ کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کافی کچھ۔۔”
فیصلے کے مطابق ان کو ہی جرمنی جانا چاہیے، ایسی درخواست میں نے کافی کی، لیکن داملے جی مانتے ہی نہیں تھے۔ شاید انھوں نے نہ جانے کا من ہی من فیصلہ کر رکھا تھا۔ آخر مجھے ہی جرمنی جانے کی تیاری کرنی پڑی۔
جرمنی پہنچنے پر جہاں تک ہو سکے بھارتی لباس میں ہی رہنے کے ارادے سے میں نے شیروانیاں، چوڑی دار پاجامے، طرح طرح کی ٹوپیاں وغیرہ کپڑے بنوا لیے۔ ماں، باپو، وِمل، میرےدونوں بچے، پربھات کمار اور دو برس پہلے جنمی لڑکی سروج میرے ساتھ بمبئی آئے۔ ان کے علاوہ پربھات فلم کمپنی میں میرے ساتھی بابوراؤ پینڈھارکر، ونائک، میرے تینوں چھوٹے بھائی کیشو، رام کرشن اور اودھوت وغیرہ سب لوگ بھی بس سے بمبئی آ گئے۔ بڑا بھائی کاشی ناتھ دادا بمبئی میں ہی رہتا تھا۔ وہ، اس کے گھر کے لوگ، بابوراؤ پینڈھارکر، تورنے اور باقی مِتر بھی بندرگاہ پر مجھے الوداع کہنے آ گئے تھے۔ ‘سیرندھری’ کی نگیٹو لے کر میں نے ‘لائڈ ٹرسٹنو’ کمپنی کے جہاز پر پاؤں رکھا۔ میں باہر ڈیک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بندرگاہ کے ساحل پر سارے خاندان والے کھڑے تھے۔ وہ سبھی ساتھی، متر ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔
میں نے بھی اپنی جیب سے رومال نکال کر ہلایا۔ وِمل ہاتھ ہلا رہی تھی اور پلو سے آنکھیں بھی پونچھ رہی تھی۔ وِمل کے پاس ہی وِنائک کھڑا تھا۔ وہ بھی پاگل جیسا رو رہا تھا۔ دھیرج اور سنجیدہ سوبھاؤ کے بابوراؤ بھی بھر آئے آنسو رومال سے دھیرے سے پونچھ رہے تھے۔ میرے بچے پربھات کمار اور سروج تذبذب میں سارا حال دیکھ رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے کام وام میں بہت زیادہ مصروف رہنے کے کارن میں نے بچوں کی طرف خاص کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ نتیجتاً وہ میرے ساتھ کوئی خاص ہلے ملے نہیں تھے۔ پھر بھی اپنے دادا کو ‘با’ کہا کرتے تھے)، وہ بھی رونے لگے۔ میری بھی آنکھیں بھر آئیں۔
جہاز ساگر ساحل کو چھوڑ کر گہرے پانی میں دور دور جانے لگا۔ ساحل پر کھڑے سبھی مرد عورت چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اور آخر میں اوجھل ہو گئے۔ تب تک میں رومال ہلا رہا تھا، اب میں نے رومال نیچے کیا اور جہاز کی ریلنگ پکڑ کر میں ڈیک پر کھڑا بندرگاہ کی سمت ایک ٹک دیکھتا گیا۔ میں سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جا رہا ہوں، ایسا نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں دور چلے جا رہے ہیں، اور میں ایک دم اکیلا رہ گیا ہوں۔ پتا نہیں کتنی دیر میں یوں ہی ڈیک پر کھڑا کھڑا کسی غیرموجود خلا میں کھوئی کھوئی نظروں سے کیا دیکھتا رہا۔۔۔۔
جہاز پر کچھ بھارتی لوگ تھے۔ ہم نے آپس میں تعارف کر لیا اور چونکہ کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا، گپیں لڑانے بیٹھ گئے۔ کئی بار جہاز پر کچھ کھیل ہوتے تھے۔ ہم سب لوگ ان میں شامل ہوتے۔ جہاز پر گھڑدوڑ بھی ہوتی۔ لیکن یہ گھوڑے ایک فٹ اونچے اور لکڑی کے بنے ہوتے تھے۔ میں نے گھوڑوں کی اس ریس میں خود پیسہ لگا کر کبھی حصہ نہیں لیا۔ میں صرف ناظر بن کر کھیل اور لوگوں کا تماشا دیکھا کرتا تھا۔ کئی بار یہ سب لوگ تاش کھیلنےجم جاتے۔ تاش میں میری تو قطعی کوئی مہارت نہیں تھی۔ گدھاکوٹ جیسے معمولی کھیل میں بھی ہمیشہ گدھا بننے لائق ہی میرا تاش کا علم تھا! ایک بار ان سب لوگوں نے مجھے بِرج کھیلنے کا آگرہ کیا۔ مجھے بِرج کے معمولی رولز پتا تھے اور ان کے بل پر میں بِرج کھیلنے ایسے بیٹھا جیسے بڑا ماہر ہوں۔ لیکن بعد میں میرے نوسِکھیا کھیل کی وجہ سے میرا پارٹنر مجھ پر بہت بگڑ پڑا۔ میں نے تاش کے پتے پھینک دیے اور چپ چاپ ایک اور چل دیا۔
سفر میں تین ہفتے بیت گئے اور ہمارا جہاز بندرگاہ پر جا لگا۔ مجھے لینے کے لیے امریکن ایکسپریس کمپنی کا آدمی آیا ہوا تھا۔ اس نے میرے کپڑوں کا بڑا بیگ، نگیٹو کے صندوق وغیرہ سامان برلن پہنچانے کا بندوبست کیا۔ پھر بھی میرے ساتھ دو تین بیگ تھے۔ وہاں سے ٹرین سے میں برلن پہنچا۔ اسٹیشن پر سامان اتروانے کے لیے میں قلی کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن وہاں کوئی قلی وُلی نہیں آیا۔ آخر میں نے خود ہی اپنا سامان اتارا۔ اپنے بیگ بھی میں نے اٹھائے ہی تھے کہ اگفا کمپنی کے ڈاکٹر پیٹرسن مجھے لِوا لینے کے لیے وہاں آ گئے۔ پیٹرسن اگرچہ جرمن تھے، انگریزی اچھی بول لیتے تھے۔
میرے ٹھہرنے کاانتظام ایک بورڈنگ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کو وہاں ‘پانسیوں‘ (Pension) کہتے ہیں۔ جس پانسیوں میں ٹھہرایا گیا تھا وہ پہلی جنگ عظیم میں گزر گئے ایک فوجی کی بیوہ کا تھا۔ پیٹرسن نے اس عورت کو میرے آرام کا دھیان رکھنے کے لیے کہا۔ جاتے وقت انھوں نے کہا، “میں کل سویرے یہاں آؤں گا۔ یہاں سے ہم لوگ اُفا سٹوڈیوز کی افِیفا لیبارٹری میں جائیں گے۔ وہاں آپ اپنے نگیٹو کی ایڈیٹنگ کا کام شروع کیجیے۔” ڈاکٹر پیٹرسن جانے کو تیار ہوئے۔ انھوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، “آف ویدرزہن!” میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ پیٹرسن نے ہنس کر کہا، “ہم جرمن لوگ ایک دوسر سے وداع ہوتےوقت ‘گڈ بائی’ نہیں کہتے، آف ویدرزہن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، امید ہے پھر ملیں گے۔” اس کے بعد میں نے بھی انھیں ” آف ویدرزہن” کہا۔
کل سے کام شروع کرنا ہے، لہٰذا کام چلانے لائق جرمن زبان کے لفظ تو معلوم ہونے ہی چاہییں، یہ سوچ کر بمبئی سے جرمن انگریزی لغت خرید لایا تھا، اسے میں نے اپنے بیگ سے نکالا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ لیکن وہ تھی نری لغت، کوئی ناول تھوڑے ہی تھا! نہ کہانیوں کی کتاب تھی! دو چار لفظوں کو یاد کرتے کرتے میری آنکھیں جھپکنے لگیں۔ آخر، کل صبح اٹھتے ہی ‘ناشتہ’ لفظ کی ضرورت پڑےگی، سوچ کر میں بریک فاسٹ لفظ کا جرمن متبادل لغت میں ڈھونڈنے لگا۔ جرمن زبان میں بریک فاسٹ کو ‘فرشسٹک’ کہتے ہیں۔ لفظ کو رٹتے رٹتے میں گہری نیند سو گیا۔
سویرے پیٹرسن آئے۔ ان کے ساتھ میں افیفا لیباریٹری جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں کچھ جرمن نوجوانوں کے دستے بڑے جوش خروش کے ساتھ حرکت کرتے جا رہے تھے۔ میں نے جوش سے پیٹرسن سے پوچھا، “یہ کون لوگ ہیں؟”
“نازی نوجوان ہیں”، انہوں نے بتایا۔ اس وقت جرمنی پر ہٹلر کے نازی وچاروں کا اثر پڑنے لگا تھا۔ ان نوجوانوں کی شرٹ کی آستین پر لال رنگ کے سواستِک بنے پٹّے تھے۔ ہاتھوں میں بندوقیں نہیں تھیں، لکڑی کے ڈنڈے تھے۔ وہ سارا منظر دیکھ کر من میں ماضی کی جنگ عظیم کی یاد تازہ ہو گئی۔ من بہت بےچین ہو گیا۔ ہماری گاڑی آگے نکلی۔ صاف ستھرا اور ایک دم سڈول برلن شہر دیکھ کر آنکھیں نہال ہو جاتی تھیں۔ ہم لوگ لیبارٹری پہنچے۔
وہاں جاتے ہی متعلقہ افسروں سے پیٹرسن نے میرا تعارف کرایا۔
بعد میں ایڈیٹنگ کے لیےمخصوص میرا کمرہ مجھے دکھایا گیا۔ میری سرپرستی میں کام کرنےجا رہی مددگار سے میرا تعارف کرایا گیا۔ یہ تمام شروعاتی رسمیں پوری کر لینے کے بعد میں نے فلم کے پہلے حصے کی جڑواں نگیٹو کی ایڈیٹنگ شروع کی۔ شام تک میں پہلی گراری تیار کر لوں تو ایک ہفتے بعد مجھے رنگین کاپی کا رزلٹ دیکھنے کو ملنے والا تھا۔
میں پہلے نمبر کی گراری کی نگیٹو کاٹ کر دیتا جا رہا تھا۔ میری مددگار جینی پاس میں بیٹھ کر جوڑوں کو ٹھیک ڈھنگ سے ایڈٹ کرتی جا رہی تھی۔ اسے کام کو سمجھا کر بتانا میرے لیے کٹھِن ہوتا جا رہا تھا۔ اسے انگریزی معمولی آتی تھی۔ اس دن انگریزی جرمن لغت اپنے ساتھ لانا میں بھول گیا تھا، لہٰذا کئی باتیں اشاروں کے سہارے ہی اسے سمجھانے کی کوشش مجھے کرنی پڑ رہی تھی۔ پہلی جڑواں گراری تیار ہو جانے پر میں نے جینی سے سامنے والی گراری پر نارنجی اور پیچھے والی پر نیلے رنگ کی فلم (Leaders) جوڑ نے کے لیے کہا۔ کیمیائی عمل کرنے والوں کو معلومات دینے کے لیے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ یہ بائی پیک سسٹم جرمنی میں بھی نیا تھا۔ نتیجتاً جینی کو بھی وہ معلوم نہیں تھا۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ نگیٹو کی سامنے والی گراری کون سی ہے اور پیچھے والی کون سی۔ “دِس از فرنٹ نگیٹو، دس از بیک نگیٹو۔”
لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ میرا منھ تاکتی رہی۔ پھر اسی نے پوچھا، “دِس واٹ؟”
میں نے اسے پھر وہی بات سمجھائی۔
اس نے ‘اب سمجھ گئی’ کی ادا سے دونوں گراریاں ہاتھوں میں لیں اور ایک کو آگے کرتی ہوئی بولی، “دِس؟”
میں نے کہا، “فرنٹ نگیٹو” اور فوراً ہی دوسری گراری کی طرف انگلی دکھا کر اسے بتایا، “بیک نگیٹو۔”
وہ الجھن میں پڑ گئی۔
میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، “دیکھو، اب تم میرے ‘سامنے’ کھڑی ہو” اور میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر ’میرے‘ لفظ پر زور دیا۔ میں آگے اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ جینی بول پڑی، “اوہ!” وہ ایک دم خوش دکھائی دی اور اسی خوشی خوشی میں جرمن بھاشا میں ‘اب سمجھ گئی’ جیسا کچھ بول گئی۔ پھر اس نے میرے سینے پر انگلی رکھ کر بڑے ٹھاٹ سے کہا، “یو مین” اور وہی انگلی پھر اپنی چھاتی پر رکھ کر بولی، “آئی گرل۔”
میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا،”اس کا مجھے پتا ہے!”
اب اس کو ‘سامنے’ اور ‘پیچھے’ لفظوں کا مطلب جرمن زبان میں کس طرح سمجھاؤں، میرے سامنےمسئلہ بن گیا۔ میں نے پھر کوشش شروع کی۔ جینی کے پیچھے کھڑا ہو کر میں نے اس سے پوچھا، “اب بتاؤ، تم کہاں کھڑی ہو اور میں کہاں کھڑا ہوں؟”
“زمین پر،” اس نے میری طرف مڑ کر ہنستے ہنستے جواب دیا۔
تُنک کر میں نے کہا، “نو نو نو!” اور ہر لفظ پر زور دے کر زور سے بتایا،
“یو فرنٹ اینڈ آئی بیک۔” میں نے اس کی طرح ہی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کا استعمال کر سمجھانا چاہا۔
لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر گئی۔ میں نے سوچا، شاید انگریزی جرمن لغت لے کر آئے گی۔ لیکن لغت کے بجاے وہ اپنی طرح وہاں کام کرنے والی دو جرمن لڑکیوں کو ساتھ لے آئی۔ میری طرف سے منھ پھیرا اور وہ ان لڑکیوں کو جرمن بھاشا میں زور زور سے کچھ کہنے لگی اور وہ لڑکیاں کِھلکِھلا کر ہنسنے لگیں۔
اب پریشانی میں مَیں پڑا۔
ان میں سے ایک لڑکی آگے آئی اور میری طرف پیٹھ کیے کھڑی جینی کی طرف انگلی دکھا کر بولی، “جینی وہورڈسٹ پرنٹ۔ .پرنٹ۔ یو سٹینڈنگ روکین بیک۔ بیک۔”
میں نے جوش کے ساتھ کہا، “یس۔۔یس۔”
‘سامنے’ اور ‘پیچھے’ ان دو لفظوں کی وجہ سے کھڑا کٹھنائی کا پہاڑ ہم لوگ پار کر چکے تھے۔
دوسرے دن افیفا لیباریٹری جاتے وقت میں نے یاد سے لغت لی۔ اس کی مدد سے میں اور جینی آپس میں تھوڑا بہت بولنے لگے۔ ہم نے اگلے نمبر کی گراری جوڑنے کے لیے لی، لیکن میرا سارا دھیان کیمیکل روم میں تیار کیے جا رہے رنگین پرنٹ کے نتائج پر فوکس ہو گیا تھا۔ ہم نےرنگین فلم کا یہ جو تجربہ ہاتھ میں لیا تھا، اس کی طرف سارا ہندوستان آنکھیں لگائے بیٹھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔
ساتویں دن سویرے پیٹرسن میرے ایڈیٹنگ روم میں آئے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انھوں نےکہا، “شانتارام، ویری سوری! بیڈ نیوز!”
لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے ساری دھرتی اور آسمان اچانک گول گھوم گئے ہیں۔
کوشش کر کے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پیٹرسن کی باتیں میں سننے لگا۔ وہ کہہ رہے تھے:
“تمہاری نیگیٹو ٹھیک طرح سے فلمائی نہیں گئی ہے۔ اس میں کافی غلطیاں ہیں اور اسی لیے اس کے رنگین پرنٹ ٹھیک سےنہیں آ پا رہے ہیں۔ اُفا کے خاص کیمیادان ڈاکٹر ولف نے تمھاری نگیٹو کے پرنٹس لینے کے لیے کئی طریقے اپنا کر دیکھ لیے، کئی تجربے بھی کیے، لیکن سب بےسود رہے! آئی ایم سوری مسٹر شانتارام!”
میرا تو گلا سوکھ گیا۔ زبان اندر ہی اندر کھنچتی چلی گئی۔ مشکل سے میں نے جیسے تیسے پیٹرسن سے پوچھا:
“تو کیا ہماری نیگیٹو کے رنگین پرنٹ بنیں گے ہی نہیں؟”
درود و سلام
درود و سلام مدح نگار: سید عارف معین بلے یہ احکم الحاکمین کا حُکم ہے کہ ان پر درود بھیجو...